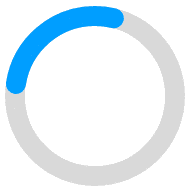مصنف: شیخ ریاض
پبلشر: پریس فار پیس فاؤنڈیشن یٰو کے
تعارف و تبصرہ کی کاوش: بُش احمد آسٹریلیا
مصنف کا تعارف: شیخ ریاض لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ اکیس سال کی عُمر میں وطنِ عزیز پاکستان کو خَیرآباد کہہ کر سمندر پار عازم سفر ہوئے (سرحد پار غالباً صحیح ہوتا کہ زمینی راستے سے ایران گئے)۔ کچھ عرصہ ایران عراق میں گزارنے کے بعد گزشتہ چون سالوں سے جرمنی میں مستقل رہائش ہے۔ جرمنی سے بی ایس سی انجنیئرنگ اور ایم ایس سی انجنیئرنگ کے بعد جرمن انڈسٹری میں کام کیا اور بعد میں اپنا الّم غلّم کاروبار۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اُردو ادب میں حالیہ شغف کی ابتدا اُردو انجمن برلن میں شمولیت سے ہوئی۔ گزشتہ چند سالوں سے فیس بُک، عالمی و قومی جرائد اور معتبر ویب سائٹس پر افسانے، کالم و مضامین لکھتے ہیں۔
(گویا کہ موصوف کوالیفائیڈ مستری بھی ہیں! زبردست!)
کتاب کے سرورق پر پہلی نظر پڑی تو دو جھنڈے نظر آئے۔ ایک پاکستان کا اور ایک جرمنی کا۔ پہلا خیال جو ذہن میں آیا کہ عُمر کا دو تہائی حصہ پردیس میں گزارنے کے باوجود انسان اپنی جنم بھومی اپنی دھرتی اپنی مٹی سے جُڑا رہتا ہے۔ اپنے وطن اور اس مُلک جس نے پناہ دی، بیک وقت دونوں سے وفاداری اخوت اور محبت کا یہ رشتہ نبھانا کتنا مشکل ہے، یہ کشمکش وہ لوگ کیسے جانیں جنہوں نے کبھی ہجرت نہیں کی۔ مُجھے یاد ہے، تیس سال قبل مَیں بذات خود، آسٹریلیا سے پاکستان مستقل رہائش کے ارادے سے گیا اور وہ بھی سب کشتیاں جلا کر۔اسلام آباد میں کسی نے مُجھ سے پُوچھا، ’’آپ دو کشتیوں میں سوار ہو کر دو مُلکوں سے وفاداری کیسے نبھا سکتے ہیں؟ آپ کی وفاداری تو دونوں مُلکوں میں مشکوک سمجھی جائے گی‘‘
مَیں نے کہا، ’’لوگ جو مرضی سمجھتے رہیں۔ میرے پاس ایک بہت سادہ سا جواب ہے جسے مَیں اپنے لئے تسلی بخش سمجھتا ہوں۔ جنگ کی صورت میں مَیں جس مُلک میں رہائش پذیر ہونگا میری وفاداری اس کے ساتھ ہو گی۔ مَیں اس وقت پاکستان میں ہوں۔ اگر آسٹریلیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو مَیں پاکستان کا دفاع کرونگا۔ اگر مَیں آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوتا اور پاکستان آسٹریلیا پر حملہ کرتا تو مَیں آسٹریلیا کا دفاع کرتا۔ اور فرض کیا، دونوں مُلک مَجھے ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی یا تخریب کاری کرنے کے لئے کہتے تو مَیں صاف انکار کر دیتا کیونکہ اُس صورتِ حال میں مَیں تذبذب اور بے چَینی کا شکار ہو جاتا جو مُجھے پسند نہیں۔ میری اپنی ذہنی صحت مُجھے بہت پیاری ہے‘‘
مصنف لکھتے ہیں کہ بعد میں بیوی بچوں سمیت جب جرمن شہریت کے لئے عرضی دی تو اپنے پاکستانی پاسپورٹ جمع کروانے پڑے کیونکہ جرمنی میں پاکستانیوں کو دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں۔
کتاب کے شروع میں جرمن جھنڈے کے ساتھ پاکستانی جھنڈا لگانے والے بندے کی اس وقت ذہنی کشمکش کا انداز ہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے والے جنرل نیازی بھی اس وقت کیا سوچ رہے ہونگے۔ نااہل پاکستانی سیاستدانوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ غَیر مُلک میں رہائشی پاکستانیوں کو اپنے مُلک کی بے عزتی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی!
مصنف نے کتاب کا انتساب ’’انسانیت سے محبت کرنے والے ہر انسان کے نام‘‘ کیا ہے۔ جس سے مَیں نے اخذ کیا کہ اپنے مُلک کی محدود سوچ سے نکل کر، اپنی یکطرفہ عَینک اتار کر، اپنے سب روایتی ہتھیارپھینک کر، بچپن کی اپنی برین واشنگ سَر کے اوپر سے اُتار کر ہی انسانیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صفحہ 13 پر مصنف میرے اس خیال کی توثیق کرتے ہیں، ’’پاکستان میں رہتے ہوئے، مُجھے کبھی بھی ایسے تجربات نہ ہوتے جو بیرون مُلک رہتے ہوئے پیش آئے۔ مَیں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ غَیر مُلک میں رہتے ہوئے مُجھے انسانیت کو سمجھنے میں بہتر مدد ملی۔ جس کو مَیں پاکستان میں تمام زندگی گزارنے کے باوجود نہ سمجھ سکتا تھا‘‘۔
شاید یہ بات صرف پاکستان پر ہی نہیں ہراُس مُلک اور معاشرے پر منطبق ہوتی ہے جہاں ماحول اختلافِ رائے کو غلط کہہ کر یکطرفہ مؤقف اپنانے پرنہ صرف اُکساتا ہے، اسے صحیح منوانے پر سرکاری سطح پر مجبور کرتا ہے۔
یہ کتاب لکھنے کا واحد مقصد مصنف کی توقع ہے کہ ان کی طویل زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے آئندہ نسلیں مستفید ہوں گی۔ خاص طور پر وہ نوجوان جو مُلک کی معاشی حالت سے مایوس ہو کر تارکِ وطن بننا چاہتے ہیں۔ انہیں جرمن معاشرے، قوانین اور دوسرے معاملات سے آگاہی ملے گی، خاص طور پر یوروپ کے حالات کے بارے میں۔
کتاب کے 23 باب خود نوشت کا احاطہ کرتے ہیں۔ کتاب میں مصنف کے لکھے گئے 9 کالموں کا متن بھی شامل ہے اور آخر میں دو افسانے بھی۔ جن پر مَیں تبصرہ یہاں نہیں کر رہا۔
کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے تجربات ہمیں خاص سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ مصنف کم عمر تھے جب ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی شفقت کے بغیر بچے کی شخصیت کیسے پنپتی ہے، اسے جاننے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے لیکن یہ امر براہ راست نہیں لکھا گیا۔ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ والد صاحب سختی کرتے تھے لیکن پیار بھی بہت۔ مصنف کا خیال ہے کہ ان کے صحیح انسان بننے میں والد کی سختی نے مدد دی تھی۔ والد صاحب بہت مذہبی تھے اور بیٹے کو مولوی یا عالمِ دین بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ پرائمری اسکول کے آخرمیں ’’وظیفے کا امتحان‘‘ ہوا۔جس سے پہلے ماسٹر جی امیدوار بچوں کے خالی پیپر جمعرات کی شام کو داتا دربار لے کر جاتے ہیں اور ان پر مجاوروں ملاؤں سے ’’پُھونک مرواتے‘‘ ہیں۔ دلچسپ بات کہ مصنف چھوٹی عُمر میں قران پڑھ لینے، سُورتیں یاد کرلینے، مذہبی جلسوں میں نعت خوانی کے باوجود بڑا ہو کر ایروناٹیکل انجنیئر بن گئے۔ شاید انہی پُھونکوں کی برکت ہو گی۔ ضروری نہیں کہ انسانی توقعات اسی انداز میں پُوری ہوں جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں۔ مصلحتِ خداوندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مولوی بن جاتے تو شاید یہ خود نوشت پڑھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ شُکر ہے کہ مصنف کو بچپن سے ہی پڑھنے کا جنون تھا، نسیم حجازی ہو یا کوئی اور، آنہ لائبریری سے لانے اور چوری چوری پڑھنے کا لُطف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کی پڑھائی بھی مصنف شوق سے کرتے تھے اور کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ آتے تھے۔ کتنا اچھا زمانہ تھا کہ وظیفے کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو ساتویں جماعت میں چار روپے ماہانہ وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ میٹرک کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ تب بھی خواہش وہی تھی جو معاشرے کی رِیت تھی کہ کسٹم، پولیس یا ایسے سرکاری محکمے میں نوکری ملے تاکہ ’’مال‘‘ بنایا جا سکے۔ لیکن ٹیوشن پڑھانا ہی نصیب ہوا۔ پھر ایک دوست کے وسیلے سے عارضی نوکری بطور کلرک مل گئی تو دوستوں کے ساتھ سَیر کرنا بھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ان کے دوست انہیں ایس ایم ریاض کے نام سے پکارتے تھے، ’’کچھ یاد نہیں کہ کیوں؟ ‘‘ اگرچہ مصنف کے میٹرک کے سرٹیفیکیٹ پر صرف محمد ریاض لکھا ہے۔
(میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایس کا دُم چھلا شیخ کا پہلا حرف ہے۔)
ذاتی وجوہات کی وجہ سے مصنف مُلک چھوڑنا چاہتے تھے۔ مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کے نام پر پاسپورٹ بنوانا مشکل نہ تھا۔ پاکستان سے بذریعہ ریل گاڑی کوئٹہ اور پھر بس سے تہران پہنچے وہاں مقیم دوسرے پاکستانیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی تجارت شروع کر دی یعنی درآمد برآمد۔ ایرانی سامان عراق کویت اور دبئی تک لیجا کر بیچنا اور وہاں کا سامان واپس لا کر ایران میں بیچنا۔موصوف لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کی نسبت عراقی سخت طبیعت والے تھے۔ جب صدام حسین نے بارہ لوگوں کو اسرائیل کی جاسوسی کےالزام میں پھانسی کی سزا دی جن میں ایک پاکستانی امیرتاجر بھی تھا تو موصوف نے عراق کو خیرآباد کہہ کر سڑکوں سڑک یوروپ جانے کی ٹھانی۔ جرمنی سے بغداد آئے ایک پاکستانی کی فوکس ویگن میں بیروت، ترکی انقرہ بلغاریہ یوگوسلاویہ آسٹریا کے راستے میونخ جرمنی میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی ۔ فیکٹری کے مینیجر کا گھر کا کوڑا کرکٹ خود اٹھا کر کچرا بِن میں پھینکنا موصوف کے لئے ’’نیا اور حیران کن منظر تھا‘‘۔
بنیادی تعلیم ٹیکنیکل نہیں تھی اس لئے جرمنی میں ووکیشنل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لئے موصوف نے جرمن ٹینک لیوپارڈ بنانے والی ایک فیکٹری میں اپرنٹس شِپ کی پھر ہوائی جہاز کی انجنیئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران میں سانس کا رشتہ برقرار رکھنے کی خاطر دیہاڑی لگائی، فیکٹریوں، شاپنگ مالز میں کام کیا۔ برفباری میں بائیسکل پر اخبارات کا پلندہ لاد کر گھروں کے پوسٹ باکسز میں اخبار ڈالے۔ کٹھن حالات کے باوجود مر مار کر بی ایس سی کی ڈگری حاصل کر لی۔جرمنی میں پیشہ ورانہ زندگی اور ویزا مسائل کی روئیداد بہت دلچسپ ہے۔ گریجوئیشن کے بعد ایٹمی پاور پلانٹ کے لئے پائپ بنانے والی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور ویزے کی توسیع بھی۔ ساتھ ساتھ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ایم ایس سی کرنے اور کبھی بطور سٹوڈنٹ اسسٹنٹ کبھی ٹیکسی ڈرائیور روزی کمانے کی تگ و دو بھی جاری۔ جرمن تعلیمی نظام میں رٹے لگا کر امتحان پاس کرنے کا امکان نہیں ہوتا۔
ایک اور دلچسپ بات کہ پاکستان میں والدین شادی پر زور دے رہے تھے. جرمنی میں کزن سے شادی کا رواج نہیں تھا۔ میڈیکل تحقیق کے مطابق جینیاتی بیماریوں کے گاڑھا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ شیخ صاحب گھبراہٹ محسوس کرتے تھے۔ لیکن خَیریت رہی۔ ایک دوست کے وسیلے سے لاہور میں شادی ہو گئی ، کراچی کی سیر بھی اور پانچ مہینے کے بعد بیگم بھی جرمنی پہنچ گئیں۔ اس کے بعد کے دلچسپ حالات پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس خود نوشت میں ایک بات جو کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے روایتی تعصبات سے چھٹکارا پانے کے لئے دوسرے مُلکوں میں کچھ عرصہ رہنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی اقدار کو بھول جائے۔ لیکن انسانیت کا رشتہ باہر نکل کر ہی سمجھ میں آتا ہے اور اپنی دھرتی سے محبت کا اندازہ بھی تبھی ہوتا ہے۔ مصنف کی تحریر میں بلا کی روانی ہے اور حالات و واقعات کا بیانیہ دلچسپ اور مربوط۔ مُجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ کہیں بھی کوئی سڑی سڑی نہیں سُٹی گئی، کسی پر بے جا الزام نہیں دھرا گیا۔ جیسا ہوا جو مشکل ہوئی اس کا سامنا بغیر شکایت کے کیا گیا۔ پاکستان کی سیاحت کے دوران اِکّا دُکّا مایوس کن واقعات ہوئے۔ مثلاً بادشاہی مسجد کے پاس عارف چٹخارے نامی ڈھابے کا کھانا بالکل پسند نہیں آیا لیکن کسی سے کچھ کہا نہیں دل آزاری نہیں کی۔حقیقی زندگی گزارنے کے لئے جس استقامت، محنت و مشقت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جرمنی میں، وہ جاننے کے لئے اس خود نوشت کا بغور مطالعہ ضروری ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔
جرمن لوگوں کی زبردست حب الوطنی کا ذکر کرتے مصنف لکھتے ہیں، ’’ہر انسان کا محب الوطن ہونا ایک قدرتی عمل بلکہ پیدائشی حق ہے لیکن جب ایک محب وطن اس حد تک وطن پرستی میں مبتلا ہو جائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے باشندوں کو دوسرے درجے کا یا حقیر سمجھنے لگے تو وہ فاشسٹ کہلاتا ہے۔ ہٹلر نے اسی فلسفے کے تحت نہ صرف جرمن قوم بلکہ تمام دُنیا کو ۔۔۔تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا‘‘
شاید ہموطنوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ جب ہم اپنی برتری کے تکبرانہ احساس سے دوسری قوموں معاشروں اقلیتوں کے بارے میں حقارت آمیز لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم فاشسزم کی خطرناک پھسلن آمیز ڈھلوان پر خود قدم دھر رہے ہوتے ہیں۔
خودنوشت میں مصنف اپنے ہونہار بچوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جنہوں نے جرمن اسکولوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ کتاب میں پاکستان کی سیاحت کا دلچسپ باب بھی ہے اور جرمنی کے سیاحتی مقامات کی جھلکیوں کا بھی۔ برلن ٹیکنیکل یونیورسٹی کی تفصیلات جرمنی میں ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمندوں کے لئے مفید ثابت ہونگی۔ یوروپ، برطانی، امریکہ، کینیڈا کا سفرنامہ بھی مزیدار ہے۔ جو لوگ وہاں جا نہیں سکتے ان کے لئے بہت کچھ ہے۔ مشہور سائنسدانوں آئن سٹائن کے گھر کی داستان مُجھے بہت پسند آئی۔
اپنے مختلف کاروباری ایڈونچر میں ناکامی اور پھر ٹیکسی سفرنامے اور دوسرے کاروباری پروجیکٹس کی روئیداد خیال انگیز ہے کہ موصوف اپنی ناتجربہ کاری، بے وقوفی اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کو الزام دیتے ہیں۔ پھر اسی باب میں لکھتے ہیں، ’’مَیں انجنیئرنگ میں گریجوئیٹ ہونے کے باوجود ہاتھ سے عملی طور پر مرمت کا کام کرنے سے قاصر ہوں‘‘۔
اچھا جی! مَیں نے آپ کو دیا گیا مستری کا تمغہ واپس لے لیا!
برلن میں اردو ادب کے تجربات کے باب میں ادبی سرگرمیوں اور شرکأ کا تعارف اور ذکرِ خیر خوب ہے۔ اللہ ان سب ادیبوں شاعروں اور سامعین کو سلامت رکھے جو پردیس میں اُردو کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔

No longer see the bSecure window?
Click Here